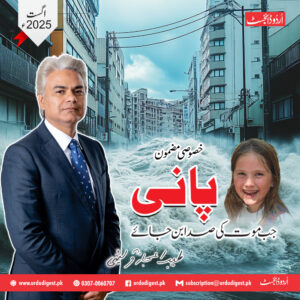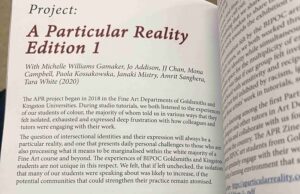اُس سہانے دور کی جاں فزا یادیںجب اہل وطن کو آزادی کی نعمت ملنے کا مژدہ سنایا گیا
الطاف فاطمہ (ادیبہ)
مَیں اُن دنوں لکھنؤ میں تھی۔
چودہ اَگست والے سلسلے میں مجھ پر جو واقعہ گزرا، مَیں کسی کو اِس لیے نہیں سناتی کہ اُس کا کوئی مشکل ہی سے یقین کرے گا۔ مَیں یہ تو نہ کہوں گی کہ تیرہ اَگست تک مَیں نے پاکستان کا نام ہی نہ سنا تھا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اِس کے متعلق کوئی واضح تصوّر اَور خیال ذہن کے کسی بھی گوشے میں نہ تھا۔ پاکستان، مسلم لیگ اور قائدِاعظم یہ سب بڑے گڈمڈ سے نام تھے اور بڑے تو بڑے، بچے بھی اِس کے نعرے لگاتے تھے۔ خود ہمارے آس پاس کے بچے اکٹھے ہو کر ایک لمبا سرکنڈا ہاتھ میں پکڑ لیتے اور ایک جتھا سا بنا کر نعرے پہ نعرے لگاتے:
’’بَٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ دُھتیا راج نہیں ہونے کا، چُٹیا راج نہیں ہونے کا، لُٹیا راج نہیں ہونے کا۔‘‘ اور مَیں نے کتنی ہی بار سرکنڈے پکڑے، اُن لونڈوں کے ہجوم کی آواز میں اپنی آواز باورچی خانے کی کھڑکی میں اکڑوں بیٹھ کر ملائی تھی۔ بھئی ایک مَیں کیا، اِس میں سب ہی تو شامل ہوا کرتے جو آج بھی مجھے مل جائیں، تو مَیں ہاتھ پکڑ پکڑ کے اُن سب کو الگ نکال کر کھڑا کر دوں۔ جو دھوتیاں باندھے، سروں پہ چوٹیاں کھڑی ہاتھوں میں ایک طرف ہندی اور دُوسری طرف اردو سے لپی تختیاں پکڑے، اُچھل اُچھل کر اور ڈٹ ڈٹ کر نعرے لگایا کرتے تھے۔
’’لے کے رہیں گے پاکستان، بَٹ کے رہے گا ہندوستان۔‘‘ اور پھر یکایک ساری سیاسی فضا بدل جاتی۔ اب وہی ہجوم لہک لہک کر یوں گانے لگتا ’’محمد علی جینا، ٹکے مہینا، چنے کی روٹی، چٹنی پودینا۔ قائدِاعظم مُردہ باد، پنڈت نہرو مردہ باد! ….. بڑے خاں صاحب کی بہن زندہ باد! ….. یوں سارا شاہ گنج زندہ باد، زندہ باد کے نعروں سے گونج جاتا۔
پھر بڑوں کی دیکھا دیکھی بچوں کی پلٹن بھی اچھل اچھل کر کہتی ’’چُٹیا راج نہیں ہونے کا، دُھتیا راج نہیں ہونے کا، لُٹیا راج نہیں ہونے کا ….. ووٹ کسے دو گے؟ بڑے خاں صاحب کی بہن کو! بڑے خاں صاحب کی بہن کو! بڑے خاں صاحب کی بہن کو! اور اَندر کی طرف آنگن والی کھڑکی کھلتی۔ سفید آڑے پاجامے اور کلی دار کرتے میں قدآور دُبلی پتلی اور سفید سر والی بڑے خاں صاحب کی بہن غصّے میں تھرتھر کانپتیں، امّاں کے پاس آتیں۔
’’سنا کچھ چھوٹی بیگم! یہ لونڈے کیسے میرے پیچھے پڑے ہیں۔ ارے یہ مجھے ووٹ کیوں دیویں، اپنے امّاں باوا کو دیویں۔‘‘
دھیمی دھیمی آواز میں امّاں اُنھیں سمجھاتیں، پان دیتیں، برف کا پانی پلاتیں اور باتوں میں لگا لیتیں۔ کبھی کبھی پچیسی کی بازی جم جاتی۔ اُنھیں ہرگز یقین نہ آتا کہ اُنھیں دلوانے والوں میں سب سے آگے اُن کی بھتیجی کے دونوں بیٹے اسلام اور خلیل ہوتے ہیں۔
وہ کوڑیاں پھینک کر اپنے گوٹ چلتے چلتے اصرار کرتیں ’’مَیں کہتی ہوں بیگم، تم اِن لونڈوں کی ماؤں کو بلا کر کہو تو ایک دن۔‘‘
یہ تھی پچھلے حصّے کی فضا۔ اگلے حصّے سے سڑک دور تھی۔ احاطے میں ایک طرف ’’ادبستان‘‘ تھا (سیّد مسعود حسن رضوی کا گھر) جہاں دس پندرہ روز تک نہ جاتی، تو مسعود صاحب امّاں سے کہلواتے تھے کہ ’’کیا آپ نے بٹو کو ہمارے یہاں آنے کو منع کر دیا ہے؟‘‘ اور پھاٹک کے عین مقابل دین دیال روڈ پر رگھبیر سہائے کا لوہے کا کارخانہ جو آتے جاتے ہمارا خیال رکھتے تھے۔ اور لوہے کے پھاٹک کی سلاخوں کے ساتھ چمٹ کر بےتحاشہ جھولتے دیکھ پاتے، تو ڈانٹ کر اُتار دِیا کرتے تھے اور دِیوالی میں شکر کے کھلونے اور کِھیلیں بھیجا کرتے تھے۔
اُن دنوں ہمارا اَخباری مطالعہ ’’پُھول‘‘ اخبار میں چھپنے والی خبروں تک محدود تھا اور اَمّاں دن بھر اپنے درختوں کی اُکھیڑ پچھاڑ میں منہمک رہتی تھیں۔
اب ایسے میں کیا پاکستان کا تصوّر وَاضح ہوتا اور کیا دل میں ارادے جمتے۔ اور اَیسے میں تیرہ اَگست کی رات کو مَیں نے جو خواب دیکھا تھا، وہ وَاقعی اب تک اچنبھا ہیمعلوم ہوتا ہے۔ ہاں تو مَیں نے کہا نا کہ دس اگست کی شام سے قمر باجی کے یہاں تھی جو میرے ماموں (سیّد رفیق حسین) کی بیٹی تھیں۔ دو دِن اچھے خاصے گزر گئے۔ تیرہ تاریخ کو سننے میں آیا کہ قمر باجی کا تو آپریشن ہو گا۔
آپریشن جیسی خوفناک چیز اور وُہ بھی ڈاکٹر رشید جہاں گھر پر کرنے کو کہتی ہیں (بعد میں معلوم ہوا کہ بعض آپریشن گھر پر بھی ہو جاتے ہیں)، پھر جو مجھے خفقان ہوا، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ’’مر جائیں اللہ کرے ڈاکٹر رشید جہاں جو آپریشن کرنے کی ضد کر رہی ہیں۔‘‘ مَیں نے اُن مرحومہ کو خوب کوسا تھا دل میں! اور بھئی کرنا ہی ہے، تو اسپتال لے جائیں، ہمارے سَر پر کیوں کر رہی ہیں۔ شام کو مَیں نے چھوٹے بھیا سے کہا:
’’مجھے گھر پہنچا دیجیے۔‘‘
اُنھوں نے مجھے جھڑک دیا۔ ’’پھر تم نے خبطنوں کی سی باتیں کیں، پہنچا دیں گے جب مناسب سمجھیں گے۔‘‘
وہ شام بڑی اداس تھی۔ شام سے آسمان پر بادل بھی تھے۔ گھمس بھی تھی اور قمر باجی کو سخت وحشت۔ اُنھوں نے مجھ سے اپنے سر میں تیل ڈلوایا۔ پھر رات گئے تک کبھی ہاتھ دبواتیں اور کبھی پیر (اُن دنوں مجھے پیر دبانے سے سخت وحشت ہوتی تھی) پھر جب مجھے اُنھوں نے نیند میں جھومتے دیکھا، تو کہا کہ تم میرے پاس ہی لیٹ جاؤ۔ ممانی جان اُن کی بچی کو لیے دوسرے پلنگ پر سو رہی تھیں۔
اب مجھے اور خفقان ہوا۔ اتنی تو یہ بیمار ہیں اور مَیں نے حسبِ عادت سوتے میں لاتیں چلائیں، تو یہ اور اِن کے ساتھ اور نہ جانے کیا کچھ مر جائے۔ مگر یہ بھی خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ اِن کا دل ٹوٹ جائے۔ کون جانے کل اِنھیں رشید جہاں مار ہی نہ دیں۔
مَیں چپ چاپ اُن کے پائنتی لیٹ گئی۔ لاتوں کے ڈر سے نیند اور نہ آ رہی تھی۔ پتا نہیں کس وقت آنکھ لگی اور کس وقت مَیں نے خواب دیکھا۔ اور اَب وہ خواب بھی سن لیجیے۔
’’جیسے کوئی بھونپو منہ میں لگا لگا کر اعلان کر رہا ہے اور مَیں لپک کر اعلان سننے گئی،تو معلوم ہوا کہ کہہ رہے ہیں، ہندو مسلمان ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، اِس لیے اب حکومت اُن پر ایٹم بم پھینک رہی ہے۔ اعلان ختم ہوتے ہی ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ فضا میں کوئی چیز بلند ہوئی (یقین جانیے وہ چیز بالکل عین راکٹ کی شکل تھی) اُس راکٹ کا رنگ بےحد خوبصورت نیلا تھا اور وُہ نیلاہٹ اِس وقت بھی میری نظر کے سامنے ہے۔
’’یکایک وہ رَاکٹ بغیر کسی آواز کے پھٹا اور دُھوئیں کی ایک دبیز چادر نے ہر چیز کو چھپا لیا۔ نہ پوچھیے کیا خوف تھا۔ مگر اچانک ہی وہ دُھواں چھٹ گیا اور قمر باجی کے گھر کے سامنے جو ٹیکرا تھا، اُس پر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ بڑی بڑی دیگوں میں کھانے پک رہے تھے اور لوگ اِسی طرح انتظاموں میں لگے تھے جیسے شادی بیاہ ہو۔ یہیں اُس ٹیکرے پر کھانے پکتے اور ہنگامے برپا ہوتے تھے۔
’’مَیں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ ابھی تو ایٹم بم گرا تھا اور ہم تو سنتے تھے سب مر جاتے ہیں اِس سے۔ اور یہاں تو آپ کھانے پکوا رَہے ہیں۔ وہ ہنس کر بولا: ہاں اِس ایٹم بم سے کوئی مرا تو نہیں مگر ہندو مسلمان الگ الگ ہو گئے اور ہندوؤں کا تو پتا نہیں، ہم مسلمانوں کے لیے یہ کھانا پکوا رَہے ہیں تاکہ اُنھیں کھلایا جا سکے۔‘‘
مَیں ہڑبڑا کر اُٹھی، بہت سویرا تھا۔ میرے اٹھنے سے پلنگ ہلا اور قمر باجی جاگ گئیں۔ اُنھوں نے مجھ سے پانی مانگا اور میری صورت دیکھ کر بولیں ’’کیوں، کیا بات ہے۔ ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ تم جا کر اُس تخت پر سو جاؤ۔‘‘
مَیں تخت پر لیٹ گئی۔ مجھے نیند نہ آئی، مسلسل ڈاکٹر رشید جہاں پر غصّہ آتا رہا۔ بس اب دس گیارہ بجے تک آ کر آپریشن کریں گی اور قمر باجی کو مار دَیں گی۔ بھئی کم سے کم میرے سامنے تو یہ نہ مریں۔ مَیں نے بھی فیصلہ کر لیا نہ ہوا، تو چپکے سے نکل جاؤں گی۔ اب اتنا بھی تو ہمارا گھر دور نہیں۔
ناشتے کے بعد اُن کے آپریشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چھوٹے بھیا شاید ڈاکٹر رشید جہاں کو لینے گئے، اتنے میں اچھن کی امّاں آ گئیں۔ امّاں نے اُنھیں خیریت پوچھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اُنھیں دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ جب وہ چلنے لگیں، تو مَیں کسی سے کہے سنے بغیر اُن کے ساتھ لگ گئی۔
امّاں نے میرے اِس طرح چلے آنے کا سن کر کہا ’’یہ تو تم نے برا کیا۔ اب بھیا ڈانٹیں گے، تو برا مانو گی۔‘‘
اب اُن سے کون کہتا کہ مَیں قمر باجی کو اَپنے سامنے مرتا دیکھنا نہیں چاہتی تھی (حالانکہ اُنھیں تو پاکستان آ کر مرنا تھا)۔ مَیں نے بات بنانے کے خیال سے کہا مَیں تو اپنا خواب سنانے آئی ہوں۔
’’کیسا خواب؟‘‘ امّاں نے پوچھا۔ اُس وقت اُن کے پاس اسلام اور خلیل کی امّاں بھی بیٹھی تھیں۔ وہ سب حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔
تعجب ہے۔ سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔
مَیں نے حیرت سے سب کی طرف دیکھا، تو امّاں نے مسکرا کر کہا ’’تمہارے خواب کی تعبیر تو مل گئی۔ آج پاکستان بن گیا۔‘‘
’’ہیں!‘‘ حیرت کے مارے میرا دِل پوری رفتار سے دوڑ پڑا۔ اُس دوپہر مَیں نے امّاں کی نظر بچا کر کھڑکی سے سبز پردہ اُتارا، ایک پرانے لٹھے کا چاند تارا کاٹا اور جلدی میں اوندھی سیدھی مشین چلا کر اُسے چپکا دیا۔ پھر بانس میں ٹانک کر اُسے چھت پر آڑا کر چپکے سے نیچے آ گئی۔
حامد علی خاں (ادیب و مدیر)
مَیں اُن دنوں دہلی میں تھا اور قرول باغ میں کشن گنج روڈ پر فیروز منزل میں رہتا تھا جو ایک بہت بڑی دو منزلہ عمارت تھی اور جس میں علاوہ مسلمان کرائےداروں کے کچھ سکھ ڈرائیور بھی رہتے تھے۔
اجمل پارک، طبّیہ کالج، پہاڑ گنج اور سبزی منڈی کے علاقے اُس کے قریب تھے جہاں بعد میں بہت قتلِ عام ہوا۔ مَیں اُن دنوں آل انڈیا ریڈیو میں اردو کا مشیرِ ادبی تھا۔ براڈ کاسٹنگ ہاؤس ایک محل نما ایئرکنڈیشنڈ عمارت تھی۔ ہندی کے مشیرِ ادبی اُس زمانے میں اوپندر ناتھ اشک تھے۔
فیروز منزل کا زیریں حصّہ پہلے میرے پاس تھا لیکن اُس میں سات آٹھ کمرے تھے۔ اور کئی کمرے ہمارے استعمال میں نہیں آتے تھے۔ اِس لیے جب بالائی حصّہ خالی ہوا، تو مَیں وہاں منتقل ہو گیا۔ میرے تعلقات مسلمان ہمسائیوں کے علاوہ سکھوں سے بھی اچھے تھے اور سیڑھیاں اترتے، چڑھتے ہوئے اُن سے اکثر علیک سلیک رہتی تھی۔
اُسی منزل کے کوارٹروں میں رہنے والا ایک ۴۵ برس کا تنومند سکھ ڈرائیور اکثر میرے پاس آیا کرتا تھا اور آ کر مجھ سے سیاسیات پر تبادلۂ خیال کیا کرتا تھا۔ جب پاکستان کا قیام یقینی ہو گیا، تو ایک دن وہ بڑی حسرت سے کہنے لگا:
’’صاحب! آپ کو آپ کا پاکستان مل گیا، ہندوؤں کو اُن کا ہندوستان مل گیا اور ہم بس یونہی رہ گئے۔‘‘
مَیں نے اُسے تسلی دیتے ہوئے کہا ’’سردار جی! اگر آپ میں بھی جذبۂ عمل قائم رہا اور آپ کا بھی ارادہ زِندہ رہا، تو یقیناً آپ بھی کامیاب ہوں گے۔‘‘
وہ کچھ نہ سمجھ سکا، چنانچہ اُس نے چڑ کر کہا ’’حکومت صاب! اب ہم سے مذاق کرتے ہو۔‘‘
جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، تو مَیں نے تہیہ کر لیا کہ کچھ دن تک دہلی ہی میں رہوں گا۔ ہمیں یقین تھا کہ دہلی میں فسادات نہیں ہوں گے۔ پاکستان بننے سے ہم بےحد خوش تھے اور سوچتے تھے کہ کیوں نہ حصولِ آزادی کی خوشی میں ہم بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کر اپنی مسرّت کا اظہار کریں۔ چنانچہ ۱۵؍اگست ۱۹۴۷ء کو ہم نے بھی یومِ آزادی منانے کا فیصلہ کیا اور اَپنے مکان پر چراغاں کیا۔
۱۵؍اگست کا دن تو خیریت سے گزر گیا لیکن اُس کے بعد ہر طرف سے بےحد تشویش ناک خبریں آنے لگیں۔ مَیں تو ریڈیو اسٹیشن چلا جاتا لیکن میری بیوی اِدھر اُدھر کی خبریں سن سن کر پریشان ہوتی رہتی۔ ایک دن اُس نے مجھے بتایا کہ نیچے ایک سکھ ایک ہندو سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان صرف نوابوں کے لیے ہے۔ یہ خان صاحب (ہماری طرف اشارہ تھا) چونکہ نواب نہیں ہیں، اِس لیے مکان چھوڑ کر پاکستان نہیں گئے۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا:
’’یہ مکان ابھی تک جلایا کیوں نہیں گیا؟ یہ ہے بھی مسلمان کی ملکیت۔‘‘
ہندو نے جواب دیا ’’یہ بھی جل جائے گا۔‘‘
سکھ نے کہا ’’اب کیا جلے گا، اب تو فساد ہی ختم ہو گیا۔‘‘
ہندو نے نہایت اطمینان سے جواب دیا ’’فکر نہ کرو، پھر ہو جائے گا فساد۔‘‘
مَیں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اُس ہندو اَور سکھ کی عمریں کیا تھیں؟
اُس نے بتایا کہ اٹھارہ اور بیس سال کے قریب۔ یہ سن کر مَیں نے اِس بات کو ہنسی میں ٹال دیا۔ میرا خیال تھا کہ ہندو اَپنے دارالسلطنت میں کوئی بڑا فساد نہیں ہونے دیں گے اور یہ محض بچوں کی باتیں ہیں۔
وہی سکھ جس نے بگڑ کر مجھے ’’حکومت صاب‘‘ کہا تھا، ایک دن میرے پاس آیا اور اِدھر اُدھر کی بےمعنی باتیں کر کے وقت ضائع کرنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی موقع کی تلاش میں ہے۔ گفتگو کے دوران اُس نے اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے رکھے۔ مجھے شبہ سا ہوا کہ شاید اِس کے ہاتھ میں کرپان یا خنجر ہے۔ لیکن مَیں نے اپنے کسی عمل سے خائف ہونے کا مظاہرہ نہیں کیا اور اِطمینان سے ہر بات کا جواب دیا۔ اُسے مجھ پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی اور اُلٹے پاؤں لَوٹ گیا۔ پھر نیچے سے چند آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ مَیں نے کان لگا کر سنا۔ وہی سکھ کہہ رہا تھا:
’’وقت آ لینے دو، پہلے اِنھیں ہی لوں گا۔‘‘
دوسری رات جب ہم فیروز منزل کی کھلی چھت پر سو رہے تھے۔ بارہ ایک بجے رات کے وقت غالباً تائیدِ غیبی سے دفعتاً ہماری آنکھ کھل گئی اور دَیکھتے کیا ہیں کہ تین ہندو مزدور دَبے پاؤں ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک ہندو، دیوان چند جو نیچے رہتا تھا، سیڑھیوں میں چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ ہم نے بڑی جرأت کے ساتھ اُن لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور برا بھلا کہا۔ اُنھیں مصلحتاً ملامت کی کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ ہم اِدھر سوتے ہیں، تو تم آئے ہی کیوں؟ وہ ٹھٹک کر رہے گئے اور اُلٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ مَیں نے آگے بڑھ کر دیوان چند کو بھی ملامت کی کہ تم نے اِنھیں اوپر کیوں آنے دیا۔ اُس نے کوئی معقول جواب نہ دیا اور آئیں بائیں شائیں کر کے نیچے اتر گیا۔
تیسری رات فیروز منزل کے اُسی سکھ ڈرائیور کے کوارٹر سے ایک پُراسرار سی آواز آنے لگی۔ یوں لگتا جیسے کوئی چیز رگڑی جا رہی ہے۔ رات کے تین بجے تک اُس کوارٹر میں روشنی رہی اور وُہ آواز بھی بدستور آتی رہی۔ تین بجے روشنی گُل ہوئی۔ اب مجھے بھی خطرے کا احساس ہوا۔ وہ باقی رات ہم نے یہاں سے جانے کی تدابیر سوچنے میں گزاری۔
صبح اٹھتے ہی ہم نے اپنے سامان کی پیکنگ شروع کی اور اِنتہائی ضروری چیزوں کے علاوہ باقی سب سامان باندھ لیا۔ پھر تانگہ لیا اور تیمارپور میں حمید احمد خاں کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سوچا تھا کہ خطرہ ٹلنے پر اپنا سامان بھی لے جائیں گے۔ فی الحال چند دن تو وہاں گزاریں لیکن جونہی ہم وہاں پہنچے، شہر میں ۸۴ گھنٹے کے لیے کرفیو لگ گیا۔ ہم بےحد پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔
ایک صبح ہندی کے ایک مشہور اَدیب بچتے بچاتے ہمارے ہاں پہنچ گئے اور پُراضطراب لہجے میں کہنے لگے آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں۔ اُنھوں نے مشورہ دِیا کہ شام سے پہلے پہلے نکل جائیے۔ غنڈوں میں ہتھیار بانٹ دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کی جانوں کو سخت خطرہ ہے۔ مَیں کئی مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اترتے دیکھ آیا ہوں۔
بڑی مشکل آن پڑی۔ سوچا کہ کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں۔ شام کے قریب بغیر کچھ سوچے سمجھے مَیں اور حمید مع اپنے اپنے کنبے کے معمولی سا سامان اٹھائے گھر چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ ہندو عورتیں اور مرد ہمیں اِس بےسروسامانی کی حالت میں جاتے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اتفاق سے ہم دریا گنج میں اسلامیہ ہائی اسکول کے ہیڈماسٹر مستنصر باللہ کے پاس جا پہنچے۔ مگر وہ خود اُن دنوں رختِ سفر باندھ رہے تھے۔ اُس رات اُن کے مکان کے صحن میں فسادیوں کی گولیاں آ کر گرتی رہیں، چنانچہ دوسرے تیسرے دن مستنصر باللہ بھی رخصت ہو گئے۔
اِس کے بعد ہم مٹیا محل کے علاقے میں مظفر ہاشمی صاحب کے خُسر کے ہاں ٹھہرے۔ مظفر صاحب اور اُن کے گھر والوں نے جس فراخ دلی اور ہمدردی کا ثبوت دیا، اُس کی یاد اَب تک دل میں تازہ ہے۔ اُن دنوں ہماری غذا تیل میں ابلی ہوئی نمکین کھچڑی ہوا کرتی تھی اور اُسے بھی ہم غنیمت سمجھتے تھے کیونکہ اشیائے خوردنی کا فراہم کرنا جُوئےشِیر لانے سے کم نہ تھا۔ بازار میں فی آدمی ایک روٹی ملتی تھی اور لاکھ کوشش کے باوجود دُوسری روٹی کا حصول ناممکن تھا۔ تنور کی روٹی عموماً ایک روپیہ یا آٹھ آنے میں ملتی تھی۔ دلّی میں ۱۹۴۵ء تک اور اِس کے بعد بھی بڑی مشکل سے راشن کا حصّہ کٹوا کر ڈبل روٹی کا کوپن ملتا تھا۔ لاہور پہنچنے پر جب فیروزپور روڈ پر ڈبل روٹیاں عام بِکتی دیکھیں، تو عجیب فرق نظر آیا۔
ایک دن شام کے وقت میرا ایک دوست مجھے ڈھونڈتا ہوا وہاں آ نکلا اور کہنے لگا کہ میرے پاس سرکاری جیپ موجود ہے اور اَبوالکلام آزادؔ کے دو باڈی گارڈ بھی ساتھ ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چل کر فیروز منزل سے اپنا سامان لے آئیے۔ مَیں اُن کے ساتھ وہاں پہنچا، تو یہ وحشت ناک منظر دیکھا کہ پوری عمارت بےشمار شرنارتھیوں کے قبضے میں ہے اور اُن کا سامان ہر طرف بےترتیبی سے بکھرا پڑا ہے۔ اپنے کمروں میں گیا، تو وہاں سامان اور کتابوں کے نام و نشان تک نہ تھے۔ پوچھا، تو پتا چلا کہ دہلی کلاتھ مِلز کے مزدور لُوٹ کر لے گئے ہیں۔ جس سامان کے لیے دل پہلے مضطرب تھا، اُسے کھو کر یوں محسوس ہوا کہ سر سے ایک بوجھ ٹل گیا ہے۔ بڑا اِطمینان محسوس ہوا۔
رخصت ہوتے وقت مَیں نے شرنارتھیوں سے کہا کہ آپ اب اطمینان سے یہاں رہیں۔ مَیں اب کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ اُس وقت ایک ہندو عورت نے مجھے دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا:
’’بھائی! تمہاری غیرحاضری میں یہ سامان لُٹا ہے۔ پرماتما تمہیں اب اُس سے دس گنا زیادہ دَے گا۔‘‘
حمید احمد خاں نے اپنے سامان کا بڑا حصّہ جان جوکھوں میں ڈال کر بچایا، کیونکہ ہندوؤں کے علاوہ مسلمان چور بھی اُنھیں لُوٹتے رہے۔ کچھ سامان اُنھوں نے اپنے ایک ہندو دوست کی تحویل میں دے دیا اور کچھ ایک مسلمان کے پاس رکھا۔ اُس مسلمان کے مکان پر بعد میں ایک سکھ کا قبضہ ہو گیا لیکن ہندو اَور سکھ دونوں نے حمید احمد خاں کو اُن کا سامان بڑی شرافت اور اِنسانیت سے لَوٹا دیا۔
مظفر صاحب کے خُسر صاحب کے ہاں ہمیں پچیس دن رہنا پڑا کیونکہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ ۲۵ دن کی تگ و دو کے بعد ملے۔ نظام محل پہنچ کر ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ 
عشرت رحمانی (ادیب)
۱۴؍اگست کا دن ….. مجھے ایک طویل طلسمی خواب کی طرح یاد ہے۔ وہ خواب جس کی آرزوئیں نامعلوم کتنی مدت گزری تھیں۔
اُس دن مَیں لکھنؤ میں تھا۔ اودھ کی خوابگوں سرزمینِ لکھنؤ ….. جہاں آج کے دن سے ٹھیک نوے برس پہلے آزادی کے متوالوں کو غلامی کی بیڑیاں پہنا دی گئی تھیں۔
مَیں صبح سویرے سے اپنے آپ کو ایک نئی فضا میں، احساسِ حیات کی نئی کشمکش میں مبتلا پا رہا تھا۔ اُس لکھنؤ میں جس کے درو دِیوار مشرقی تہذیب سے منورّ تھے۔
مجھے لکھنؤ آل انڈیا ریڈیو کے ساتھ منسلک رہتے ۱۹۴۷ء میں آٹھ سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ لکھنؤ کی فضا ہر اعتبار سے خاصی خوشگوار تھی اور خصوصاً ریڈیو اسٹیشن کے عملہ میں تو غیرمعمولی اتفاق اور یک جہتی قائم تھی۔ آزادی کے آثار جُوں جوں قریب تر نظر آ رہے تھے، ظلمتیں بڑھ رہی تھیں۔ ہنگامے، فسادات، شوروشر، قتل و غارت، غرض سارا ملک عجیب افراتفری میں مبتلا تھا۔ جب کبھی ہمارے عملے میں پاکستان کے قیام کا ذکر چھڑتا اور مسلمان اہل کاروں کے تبادلے کی بات شروع ہوتی، تو غیرمسلم اہل کار تمام مسلم عملے کے گرد جمع ہو جاتے اور شور مچاتے ’’ہم تمہیں کہیں نہ جانے دیں گے۔‘‘
اُس وقت ایک عجیب رنگ نمایاں ہوتا۔ آپس میں گلے مِل مِل کر کہتے ہم لکھنؤ کیوں چھوڑیں گے۔ اور وَاقعی ہمارے لیے لکھنؤ سے رخصت ہونا آسان نہ تھا۔ مَیں نے آٹھ سال کی مدت میں کئی بار ترقی سے دست برداری لکھی تھی اور تبادلہ منسوخ کرایا تھا۔ آخر پاکستان کے قیام کا باضابطہ اعلان ہو گیا۔ جب ہمارے عملے کے تمام اہل کاروں سے ’’اوپشن‘‘ کے لیے سرکاری طور پر دریافت کیا گیا، تو سوچنے سمجھنے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ تمام مسلم اہل کار یک زبان ’’پاکستان، پاکستان‘‘ پکارنے لگے۔ مَیں نے سب سے پہلے پاکستان قبول کیا۔ اب مَیں اِس لکھنؤ سے رخصت ہونے کو آمادہ تھا جس سے ایک لمحے کی جدائی کا تصوّر سوہانِ روح تھا۔ مگر ہم تو پاکستان جا رہے تھے۔ ہم سب پاکستانی تھے جس پر غیرمسلم ساتھیوں کو حیرت، غصّہ اور اَفسوس نجانے کیا کچھ تھا۔
بہرحال شروع اگست میں سارا مسلم عملہ لکھنؤ سے ڈھاکا کے لیے روانہ ہو گیا کیونکہ ہم سب کے حصّے میں ڈھاکا اسٹیشن آیا تھا۔ اُس وقت پاکستان کے علاقے میں کُل تین ریڈیو اسٹیشن تھے ’’لاہور، پشاور اَور ڈھاکا۔‘‘
لیکن مجھے کچھ عرصہ مجبوراً لکھنؤ رہنا پڑا، کیونکہ مَیں اُس زمانے میں ایک دوست کی فلم ’’سنگھم‘‘ آئیڈیل فلمز، لکھنؤ کے اسٹوڈیو میں ڈائریکٹ کر رہا تھا۔ اِس کے علاوہ میری والدہ صاحبہ بھی علیل تھیں۔ بہرحال ۱۴؍اگست کی صبح طلوع ہوئی جو پاکستان کے قیام اور آزادی کا مژدۂ جانفزا لائی۔ آج بھی وہی سورج تھا جو کل طلوع ہوا تھا۔ لیکن کل وہ آج کی طرح سُرخرو نہ تھا۔ آج اُس کی شعاعوں سے نغمے ابل رہے تھے۔ آج اَن سنے گیتوں کی پھوہاریں ٹپک رہی تھیں۔ مَیں نے جشنِ پاکستان کی اَن دیکھی بہاروں کی یاد میں اپنا پہلا قومی گیت لکھنا شروع کیا ؎
میرا وَطن ہے پاکستان!
اِس پر صدقے دین، ایمان
روح مسرّت سے جھوم اُٹھی ….. ریڈیو کھولا ….. نویدِ حیرت سنائی دی:
’’پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس‘‘
سماعت پر یقین نہ آیا۔ عقل نے ہوش سے سوال کیا ’’کیا واقعی پاکستان منصہ شہود پر آ گیا۔‘‘
ڈاکٹر احرار نقوی
اُن دنوں مَیں ساتویں جماعت کا طالبِ علم اور سیتاپور میں رہتا تھا جو لکھنؤ سے اتنا قریب ہے کہ بس لکھنؤ کا ہی ایک گوشہ سمجھیے۔ محمودآباد سیتاپور ضلع کا ایک حصّہ تھا۔ راجہ محمودآباد کی وجہ سے سیتاپور تحریکِ پاکستان کا ایک بہت بڑا گڑھ بن گیا۔ میرے والد ڈاکٹر محمد ادریس شہر کے عمائدین میں شمار ہوتے تھے۔ جب وہ مسلم لیگ تحریک سے منسلک ہوئے، تو پھر ایسے جذباتی ہوئے کہ جی اور جان کی بازی لگا دی۔ گھر سے باہر کبھی چار قدم بھی وہ بِن سواری کے نہ نکلتے تھے مگر پاکستان کی تخلیق کی خاطر اُنھوں نے گھربار چھوڑ کر گلیوں گلیوں خاک چھانی، بھوکے پیاسے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اور مجھے بھی انگلی پکڑ کر قوم کے نام پر مر مٹنے کا درس سکھا دیا۔
بس میرے شعور نے جب آنکھیں کھولیں، تو یہی ماحول دیکھا۔ جھنڈے نکالنا، ننھے منے مجاہدوں کا جلوس نکالنا، نعرے تراشنا، نظمیں پڑھنا یہی میرا حسین مشغلہ بن گیا۔ جھنڈا اَپنے ہاتھ میں لینے کی ضد، جلوس کے سب سے آگے رہنے پر تکرار، یہ تھا بچپن کا جھگڑا اور کھیل۔ یہ کھیل ایسا تھا جس میں والدہ محترمہ بھی شریک، والد بزرگوار بھی رفیق، پیاری بہنیں بھی معاون اور بڑے بھائی بھی ہمدرد۔ ہم لوگوں کا بس ایک وظیفہ تھا:
بَٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان
رات کو لیٹتے، تو یہ وظیفہ پڑھتے، صبح کو اُٹھتے،تو اِسے کلمے کے طور پر پڑھتے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تو ننھے ننھے ہاتھوں سے دعا مانگتے۔ مسجدوں میں جاتے، تو سب مل کر اپنے معبود سے یہ گِڑگڑا کر دعا کرتے:
’’اے بارِ الٰہا! قوم کی آبرو کا تُو ہی نگہبان ہے۔ اِس ڈوبتی کشتی کا تُو ہی کھیون ہار ہے۔‘‘
۱۴؍اگست ۱۹۴۷ء منتوں اور مرادوں کا دن تھا اور اَیسی خوشی تو نہ کبھی عید کی تھی نہ بقر عید کی۔ اللہ اللہ وہ دِن جب آیا، تو پورا شہر جگمگاتے ہوئے چراغوں سے روشن ہو گیا۔ آزادی کے نغمات فضا میں گونج اٹھے۔ چاروں طرف نور کی بارش ہو رہی تھی۔ میرا دو منزلہ مکان بھی چراغوں کی روشنی سے دلہن بنا ہوا تھا۔ باہر کے کمرے شہر کے معززین سے کھچاکھچ بھرے ہوئے تھے جو جوق در جوق والد صاحب کو پاکستان کی مبارک باد دَینے چلے آ رہے تھے۔ ہاں مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ قدرے مایوسی کے انداز میں مَیں نے اپنے بڑے بھائی (ابوالحسن نغمی) سے پوچھا تھا:
’’اچھا ….. کیا پاکستان ہمارے شہر میں نہیں بنے گا؟‘‘
….. اور میرے بھائی، میرے بچپن کے انیلے پن پر بےساختہ مسکرا دِیے تھے۔ مگر کسی کو کیا علم تھا اِس انیلے نٹ کھٹ لڑکے کا وطن، شہر لاہور ہو گا۔
رئیس احمد جعفری (مورخ و اَدیب)
۱۴؍اگست ۱۹۴۷ء کو مَیں بمبئی میں تھا۔
بمبئی ….. قائدِاعظم کا مسکن، تحریکِ خلافت کا مرکز، ’’ہوم رول لیگ‘‘ کا مرکزِ ثقل، کانگرس کا غیرسرکاری صدر مقام، کانگرس کے تعمیر کیے ہوئے ’’جناح ہال‘‘ کا شہر، ہندوؤں اور مسلمانوں کی طوفاں بدوش سیاسی تحریکوں کا مستقر اور مسلم لیگ کی تحریکِ پاکستان کا گہوارہ!
بمبئی نے مسلم لیگ کو بہت کچھ دیا۔ بےاندازہ دَولت اور بےانتہا سرمایہ بھی، سرفروش اور جان نثار رَضاکاروں کے دستے بھی، قوتِ عمل بھی، جذبۂ کار بھی، قربانی کا ولولہ بھی، سر کریم بھائی ابراہیم (بیرونٹ) جیسا جیالا سپاہی بھی۔ مسٹر چندریگر جیسا عالی دماغ سیاست دان بھی۔ حاجی نور اَحمد جیسا منچلا عوامی رہنما بھی اور مسٹر جناح جیسا عہدآفریں قائدِاعظم بھی۔
مَیں ایک روزنامے کا ایڈیٹر تھا۔ مَیں نے اپنے قلم سے تلوار کا کام لیا تھا لیکن آج یہ تلوار میان میں چلی گئی تھی۔ ہندوستان آزاد ہو گیا تھا، پاکستان عالمِ وجود میں آ گیا تھا
….. بنیں گے اور ستارے اب آسماں کے لیے!
آج سارے اختلافات مٹ گئے تھے، ساری تلخیاں دور ہو چکی تھیں، سارے مناقشے ختم ہو چکے تھے، ماضی کو فراموش کر کے حال کا شاندار اِستقبال کیا جا رہا تھا۔
ایک بہت بڑا جلوس نشاط و طرب کے نغمے گاتا بمبئی کی سڑکوں پر گشت کر رہا تھا۔ اُس جلوس میں ہندو اَور مسلمان دوش بدوش مسرّت کا اظہار کر رہے تھے، گلے مل رہے تھے۔ ایک دوسرے کو مبارک باد دَے رہے تھے۔ آج مسلمان کے لیے ہندو آبادی میں اور ہندو کے لیے مسلم آبادی میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔
آج کسی کے پیٹ میں خنجر نہیں گھونپا گیا، آج کسی کا سینہ پستول کی گولی سے نہیں چِھدا۔ آج کسی کی گردن نہیں کٹی، آج کوئی سہاگن بیوہ نہیں ہوئی، نہ کوئی بچہ یتیم ہوا۔ آج سڑک پر خونِ ناحق کے چھینٹے اڑے نہ کسی بےگناہ کے حلقوم و گلو سے خون کا فوارہ چُھوٹا۔ آج کا دن عید کا دن تھا، عیدِ آزادی کا دن۔ جشنِ استقلال کا دن، عروسِ حریت سے ہمکنار ہونے کا دن ….. حوریاں رقص کناں ساغر مستانہ زوند!
لیکن یہ خوشی صرف ایک دن کی تھی، اِس جشن کی عمر چند گھنٹے سے زیادہ نہ تھی۔ رات گزرتے ہی پھر وہی کشاکش اور کش مکش۔ پھر وہی ہندو مسلم آویزش، مسلمانوں سے اظہارِ وَفاداری کے تقاضے، اعلانِ اطاعت کے مطالبے، ہندوستان آزاد ہو گیا تھا، لیکن مسلمان غلام بن گئے۔ اُن کے آقا بدلے تھے، قسمت نہیں بدلی تھی۔
مَیں نے پھر اپنا قلم سنبھالا ’’من و گُرز و میدان و اَفراسیاب!
چند روز بعد ہوم ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے ایک نوٹس ملا جس کی رُو سے پریس کمیٹی میں اصالتاً مجھے حاضر ہونا چاہیے تھا جہاں میرا مقدمہ پیش ہو رہا تھا۔پریس
کمیٹی کے صدر اَز رُوئے منصب مرارجی ڈیسائی، وزیرِ داخلہ بمبئی تھے اور اَز رُوئے تعامل یہ منصب سیّد عبداللہ بریلوی ایڈیٹر بمبئی کرانیکل کو حاصل تھا۔ ممبروں میں سر فرانسس لو، ایڈیٹر ٹائمز آف انڈیا اور ایک گجراتی اخبار کا ہندو اِیڈیٹر شامل تھا۔
مَیں مقررہ وَقت پر پہنچ گیا۔ سر فرانسس لو، بریلوی صاحب اور متعدد ممبر آ چکے تھے۔ سر فرانسس لو نے کرسیٔ صدارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بریلوی صاحب سے کہا:
’’آئیے، اب کارروائی شروع ہو جانی چاہیے۔‘‘
بریلوی صاحب مسکرائے اور کرسیٔ صدارت پر متمکن ہونے ہی والے تھے کہ دفعتاً دروازہ کھلا ….. اِس تکلف سے کہ گویا بُت کدے کا گھر کھلا!
ایک خوش رُو، خوش رنگ، خوش وضع شخص نمودار ہوا۔ گورا رَنگ جس میں خشم و عتاب کی سرخی بھی شامل تھی، کشیدہ قامت، آہو چشم اور ….. قدِ رعنا میں وہ دَم خم کہ بلائیں بھی مرید۔ ایسا معلوم ہوا کہ صنم کدے کے پَٹ کھلے، ایک بُت عربدہ جلوہ نما ہوا اَور آتے ہی کرسیٔ صدارت پر متمکن ہو گیا۔ بےچارے بریلوی صاحب منہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ تھے مرار جی ڈیسائی۔
میرا مقدمہ پیش ہوا۔ مرار جی نے مجھ سے سوال کیا:
’’آپ کارروائی انگریزی میں چاہتے ہیں یا …..؟‘‘
مَیں نے قطع کلام کرتے ہوئے عرض کیا:
’’انگریزی نہ آپ کی زبان ہے نہ میری، گجراتی صرف آپ کی زبان ہے۔ اردو ہم دونوں کی زبان ہے، لہٰذا وُہ بہتر رہے گی۔‘‘
مرار جی کا چہرہ کچھ اور تمتما گیا لیکن خاموش بیٹھے رہے۔ کارروائی اردو میں شروع ہوئی۔ میرے تین مقالاتِ ادارت حاضرین کو سنائے جانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد مرار جی کا پیمانۂ صبر چھلکا۔ اُنھوں نے مداخلت کرتے ہوئے سوال کیا:
’’آپ اب تک پاکستان کیوں نہیں گئے؟‘‘
مَیں نے سوال کیا ’’کیوں جاؤں؟‘‘
’’وہ آپ کا وطن ہے۔‘‘
’’میرا وَطن وہ ہے جہاں مَیں موجود ہوں۔‘‘
’’کیا آپ قیامِ پاکستان کے پُرزور نقیب نہیں تھے؟ کیا آپ نے اپنا قلم تائیدِ پاکستان کے لیے وقف نہیں کر رکھا تھا؟‘‘
’’ہاں! مَیں نے یہ کیا تھا کہ لیکن تُرکوں کی آزادی کے یے بھی یہی کیا تھا مگر انگریزوں نے کبھی نہیں کہا، قسطنطنیہ چلے جاؤ۔ مصر کے لیے بھی کیا تھا مگر انگریزوں نے کبھی شاہراۂ بغداد کی جانب اشارہ نہیں کیا۔ ایران کے لیے بھی کیا تھا مگر انگریزوں نے نہ ہم سے اظہارِ وَفاداری کا مطالبہ کیا نہ سم و طاعت کی بیعت لی۔ نہ کھرید کھرید کر تہران بھیجا۔ آپ کیوں میرا وَطن مجھ سے چھڑانا چاہتے ہیں؟‘‘
مرار جی نے زہرخند کرتے ہوئے حاکمانہ دبدبے کے ساتھ مجھے گھورا۔ گویا زبانِ خاموش سے فرما رہے تھے ’’شعلہ ہوں بھبھوکا ہوں، غضب ہے مرا غصّہ!‘‘ پھر فرمایا:
’’آپ کا وطن پاکستان ہی ہے۔ آپ کو چلے جانا چاہیے۔ آپ کو جانا پڑے گا۔‘‘
یہ فرمایا اور برہمی کے عالم میں اُٹھ کر چلے گئے۔ مَیں دل ہی دل میں کہتا رہ گیا ؎
کس کس طرح ستاتے ہیں یہ بُت ہمیں نظامؔ
ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو
اور بالآخر جنوری ۱۹۴۸ء میں اِن سطروں کو لکھنے والا پاکستان آ گیا اور آنے کے بعد حالت یہ ہوئی کہ ؎
پھرتے ہیں میرؔ خوار کوئی پوچھتا نہیں
اِس عاشقی میں عزتِ سادات بھی گئی